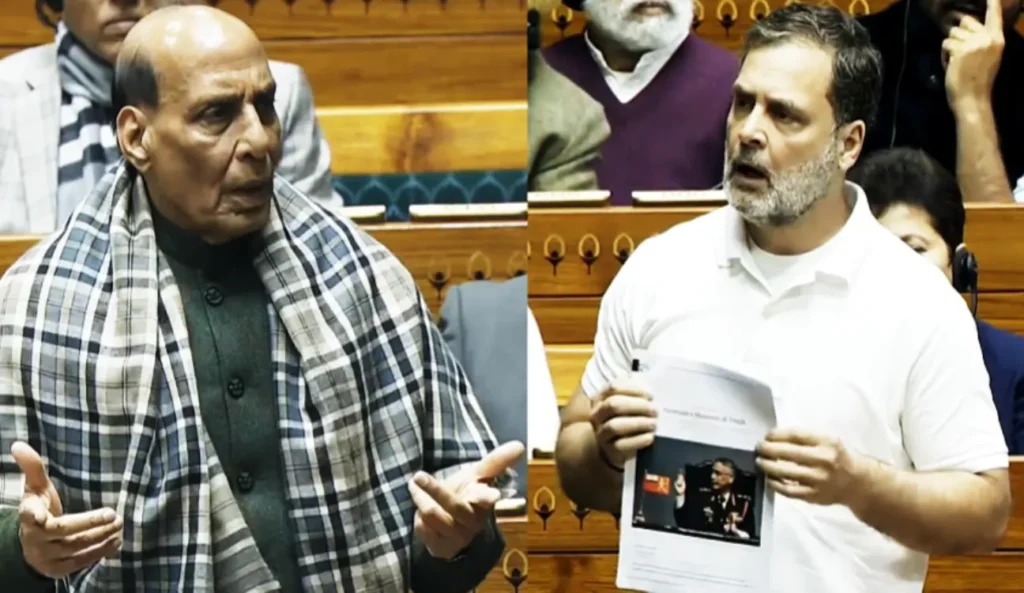اقبال کا تصور ادب

محمد ساجد ندوی
ریسرچ اسکالر: جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
علامہ محمد اقبال کے شعری سفر اور فکری و تعقلاتي جہان ميں تضادات کی خاص اہميت ہے۔ اردو کی شعری و ادبی روايت ميں اقبال کے يہاں جس قدر تضادات پائے جاتے ہيں، کسی دوسرے شاعر و اديب کے يہاں ہميں نہيں ملتے۔ تضادات کا يہ پورا نظام بعض ناقدين کے نزديک اقبال کی عظمت کی ايک بڑی وجہ ہے، جب کہ بعض اسے اقبال کی علمی کم مائيگی يا فکری ژوليدگی سے تعبير کرتے ہيں۔ اقبال کے تصور ادب ميں بھي تضاد کی يہی صورت جلوہ گر ہے۔ فن کی سطح پر اقبال شعريت کي بلند چوٹی پر متمکن ہيں جب کہ اپنے بيانات ميں خود کو بہ طور شاعر تسليم کيے جانے کے روادار نہيں۔
اقبال کے شعری و نثري سرمائے کی روشنی ميں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اقبال کے يہاں مقصد اصل ہے، فن کی حيثيت ثانوی يا آلہ کار کی ہے۔ ليکن اقبال کی شاعری ميں موضوع اور ہيئت کا اس قدر کام ياب امتزاج پايا جاتا ہے کہ عملی سطح پر فيصلہ مشکل ہوجاتا ہے کہ ان کی نظر ميں زيادہ اہميت کسے حاصل ہے۔ ذيل ميں اقبال کے فکر و فلسفے کي روشنی ميں اقبال کے تصورِ ادب کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔
جب بھی کسی بڑے شاعر يا اديب کا مطالعہ اس کے ادبی تصور کے حوالے سے کيا جاتا ہے تو عام طور سے يہی ديکھا جاتا ہے کہ فلاں کے نزديک موضوع اہم ہے يا ہيئت؟ اور پھر دونوں ميں سے کسی ايک کی طرف اس اديب کے ذہنی ميلان کو ثابت کر کے فيصلہ سنا ديا جاتا ہے۔ يعنی فلاں اديب کے نزديک ادب برائے ادب يا فن برائے فن مقدم ہے۔ يا پھر يہ کہ فلاں ادب برائے زندگی کا علم بردار ہے۔ ادب برائے زندگی کے حامی شعرا و ادبا بھی ايسا نہيں ہے کہ دانستہ فن کی طرف سے اغماض برتتے ہوں بلکہ مقصديت کا جذبہ اس قدر شديد ہوتا ہے کہ فن کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے۔
اقبال پر بات کرتے ہوئے بيش تر ناقدين لکھتے ہيں کہ اقبال ادب برائے ادب کي بجائے ادب برائے زندگی کے قائل تھے۔ يہ جملہ وضاحت طلب ہے۔ کيوں کہ ماضی ميں ادب برائے زندگي کو ترقي پسند تحريک کے ساتھ اتنا جوڑا گيا ہے کہ يہ اصطلاح جب کسی اديب و شاعر کے ليے استعمال کی جاتی ہے تو يہی لگتا ہے کہ اس کا رشتہ ترقی پسند تحريک سے ضرور ہوگااور پھر اقبال سے ترقي پسندوں نے تو عنديہ بھي لے ليا تھا۔ اس ليے اس کی تفصيل ضروری ہو جاتی ہے۔ اقبال کا خيال تھا کہ ادب کو زندگی کے اعلیٰ نصب العين کے حصول ميں معاون و مددگار ہونا چاہيے۔ يہی نعرہ ترقی پسند اديبوں کا بھی رہا ہے۔ سوال پيدا ہوتا ہے کہ ترقی پسند اديبوں اور دانشوروں کی طرح اقبال بھی جدلياتی و طبقاتی کش مکش کے قائل ہيں يا پھر وہ زندگی کے نصب العين کو اس سے بالاتر تصور کرتے ہيں۔ ميرے خيال ميں اقبال کے تصور ادب کو ادب برائے زندگی اور زندگی برائے بندگی سے تعبير کيا جا سکتا ہے۔ کيوں کہ وہ انسان کے منصب نيابت کے قائل تھےاور ان کا مشن اسی منصب جليلہ پر امت کو فائز کرنا تھا۔ حالاں کہ اس ميں بھی کش مکش موجود ہے اور مقتدرہ کے حصول کي کوشش کا نظريہ اقبال کے يہاں بھي موجود ہے، ليکن ان کے يہاں سارا معاملہ حق و باطل کا اور امن و فساد کا ہے۔
يہ بات فراموش نہيں کرنی چاہيے کہ کسی بھی ادب کا خمير اس کے اپنے تصور تہذيب سے تيار ہوتا ہے، دوسرے لفظوں ميں ادب تہذيبي زندگي کا آئينہ ہوتا ہے۔ اور اقبال کے تصور تہذيب ميں فرد اور جماعت کو خاص مقام و اہميت حاصل ہے۔ کيوں کہ اقبال زندگي کو کلي اور نامياتي طور پر ديکھتے تھے۔ ان کے يہاں انسان کا بھي ايک جداگانہ تصور تھا، جس ميں خدا کي تخليق ہونے کے ساتھ ساتھ اس ميں خلق کرنے کي بھي چاہت موجود ہے۔ يہي وجہ ہے کہ وہ ادب کو گردش دوراں کے ساتھ اس کے مدار کو تبديل کرتے رہنے پر زور ديتے ہيں۔
علامہ اقبال اردو کے واحد ايسے شاعر ہيں جنھوں نے اپنی شاعری اور نثری بيانات دونوں کے ذريعے سے خود کو محض شاعر يا اپني سخن سنجی کو نری شاعری تسليم کرنے سے انکار کيا ہے۔ مندرجہ ذيل شعر ميں اقبال کا شاعرانہ مسلک نماياں ہو کر سامنے آتا ہے:
نغمہ کجا و من کجا سازِ سخن بہانہ ايست
سوئے قطار مي کشم ناقہ بے زمام را
اقبال کو اپنی قوم سے اسی ليے شکايت بھي ہے، وہ فرماتے ہيں:
او حديث دلبري خواہد زِمن
رنگ و آبِ شاعري خواہد زِمن
کم نظر بے تابيِ جانم نديد
آشکارم ديد و پنہانم نديد
اقبال کے اردو کلام کی بات کريں تو وہاں يہ کہتے ہوئے دکھائی ديتے ہيں:
وہ شعر کہ پيغام حيات ابدی ہے
يا نغمہ جرس ہے يا بانگ اسرافيل
اسی طرح يہ بھي کہتے ہيں کہ:
ہوئی ہے زير فلک امتوں کي رسوائی
خودی سے جب ادب و دين ہوئے ہيں بيگانہ
اسي طرح اپنے نثری بيانات ميں بھی واضح طور پر انھوں نے فن کے بجائے مقصديت کو اپنا ادبی مسلک قرار ديا ہے۔ فنون لطيفہ اور خودی کے تعلق سے اقبال اپنا موقف اس طرح بيان کرتے ہيں:
‘’مجھے جو کچھ کہنا ہے، اس کا حاصل بس اس قدر ہے کہ ميں سارے فنون لطيفہ کو زندگی اور خودي کے تابع سمجھتا ہوں۔’‘
(ديباچہ مرقع چغتائي، در مضامين اقبال، ص ۱۹۷ )
سيد سليمان ندوی کے نام ۲۰ اگست ۱۹۳۵ کے اپنے ايک خط ميں اقبال بہت وضاحت کےساتھ لکھتے ہيں:
‘’ميں نے کبھی اپنے آپ کو شاعر نہيں سمجھا۔ اس واسطے کوئی ميرا رقيب نہيں اور نہ ميں کسی کو اپنا رقيب تصور کرتا ہوں، فنِ شاعری سے مجھے کبھی دل چسپی نہيں رہی، ہاں بعض مقاصد خاص رکھتا ہوں جن کے بيان کے ليے اس ملک کے حالات و روايات کی رو سے ميں نے نظم کا طريقہ اختيار کر ليا ہے۔’‘
اس کے باوجود اقبال کي شاعرانہ عظمت سے انکار کي جرأت کسی ناقد کو نہ ہو سکی اور آج بھی اقبال کے فکر کے ساتھ ساتھ اس کے فن پر بھي گاہ گاہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ دراصل اقبال نے دنياے ادب کے لازوال شاہ کاروں کا سراغ پا ليا تھااور وہ اسی راہ پر چل نکلے تھے کہ کسی بھی فن کی ادبی روايات سماجی و لسانی عوامل کے بدلاؤ سے کہنہ اور فرسودہ ہوجاتی ہيں، اسی وجہ سے انھوں نے اپنے افکار و نظريات کي ترسيل و ابلاغ ميں زمان و مکاں کي قيد کو مٹا دينے يا کم کرنے کی کوشش کی۔
اقبال نے اپنے فکر و فن کو جلا بخشنے کے ليے دنيا بھر کے مفکرين اور ان کے افکار و آرا سے بھرپور استفادہ کيا ہے، ليکن ان کے يہاں آکر ان سبھی موضوعات و روايات کي صورت يکسر بدل گئی ہے اور اقبال کے ذہن کی بھٹی ميں پک کر بالکل چيزے ديگر تيار ہوئی ہے۔ بعينہ اسی طرح جيسے قدرت کے پاس حضرت انسان کا ڈيزائن اور نقشہ موجود تھا اور اس نے اسی جہان سے آب و گل کو اٹھا کر اور کھنکھناتی مٹی سے انسان کا خمير تيار کيا اور پھرگوشت و پوست کا آدمی تيار ہوگيا، ويسے ہي اقبال نے قرآن حکيم کے کنہ تک پہنچنے کی کوشش کی اور پھر اس کے ابلاغ کے ليے دنيا بھر کے افکار و نظريات، افراد و اشخاص اور ادبی رجحانات و تصورات کا اپنے کلام ميں استعمال کيا اور ايک نظام فکر و عمل کی تشکيل کر ڈالی۔ چناں چہ اقبالياتی ادب يا اقبال کے تصور ادب کو سمجھنے کے ليے ضروری ہے کہ اقبال کے فلسفۂ حيات و کائنات کا فہم حاصل کيا جائے۔
شعر برائے شعر اقبال کے مزاج و مذاق کے منافی تھا۔ يہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں تجربے کے نام پر ادبی قلابازياں ديکھنے کو نہيں ملتيں۔ انھوں نے مقتضائے حال کے مطابق فنی اقدار و روايات کی مکمل پاسداری کی ہے۔ البتہ ادبی موضوعات کے اختيار و برتاؤ کے معاملے ميں ان کے جذبہ دروں کي جھلکياں صاف دکھائی ديتی ہيں۔ اقبال کی تحريريں خواہ نثر ہو يا شعر، پڑھتے ہوئے قاری کو محسوس ہوتا ہے کہ اقبال ايک داخلی کرب اور ذہنی تناؤ کا شکار ہيں، ذہن کے پردے پر معنی کا ايک سمندر موجزن ہے جو اظہار و ابلاغ کے ليےنہايت تنگ نالوں سے بہہ نکلنے پر مجبور ہے۔ چناں چہ اقبال کو دنيائے ادب و فن کے کسی بھی ذخيرے ميں شرقی اور غربی ہوئے بغير اظہارِ ذات و کائنات کے ليے جہاں گنجائش ملی، اختيار کر ليا۔ جہاں ايک طرف اقبال اردو فارسی روايات ميں موجود کلاسيکی احتمالات و امکانات کا دامن تھامتے ہيں، وہيں رومانيت بھی آپ کے نوک قلم کے ساتھ عناں گير ہوتی ہے۔ اور پھر تلميحات کے استعمال سے علامتوں کا ايک پورا نظام تشکيل پاتا ہے۔ يعنی کلاسکيت، رومانيت اور رمزيت اقبال کی شاعری ميں تينوں کی روح کارفرما ہے۔
اقبال جب اپنی تحريروں ميں اس بات کا اظہار کرتے ہيں کہ شاعری ان کا مطمح نظر نہيں، يا وہ نہيں چاہتے کہ زمانہ ايک شاعر کي حيثيت سے انھيں ياد رکھے، تو قاري کو يہ انديشہ لاحق ہوسکتا ہے بلکہ ہمارے بعض ناقدين کو ہوا بھی ہے کہ اس طرز عمل سے ترقی پسندوں ہي کي طرح اقبال کے يہاں بھی فن کہيں پيچھے رہ گيا ہے اور مقصديت کے نيچے دب گيا ہے۔ چناں چہ بعض ناقدين و محققين کو ان کے کلام ميں فنی اسقام بھی نظر آئے ہيں۔ حالاں کہ غير جانب داری کے ساتھ جن ناقدين نے اقبال کي شعری کائنات کا مطالعہ کيا ہے انھيں کہيں بھی اس طرح کی فنی اغلاط نظر نہيں آئی ہيں۔ اس حوالے سے گيان چند جين، جگن ناتھ آزاد، شمس الرحمن فاروقي، گوپي چند نارنگ اور عبد المغنی کی آرا کا مطالعہ کيا جا سکتا ہے۔ شمس الرحمٰن فارقی کے نزديک مير و غالب نے بھی بحر کے معاملے ميں کہيں نہ کہيں ٹھوکرکھائی ہے، ليکن اقبال کے يہاں کوئي عروضی غلطي نہيں ملتی۔ گيان چند جين نے تو بڑی عرق ريزی اور فنی بصيرت سے کام ليتے ہوئے اقبال کے پورے اردو کلام کي تقطيع کر کے ايک جدول تيار کيا اور ثابت کيا کہ صرف ايک مصرع اقبال کے يہاں مخدوش ہوا ہے:
اقبال بڑا اپديشک ہے من باتوں ميں موہ ليتا ہے
اس ميں اقبال نے ’موہ‘ جو ’مہ‘ کے وزن پر باندھا ہے۔ ليکن فاروقی نے اسے گيان چند جين کي سخت گيري سے تعبير کيا ہے۔ کيوں کہ فارسی کے بہت سے الفاظ جو واؤ اور ہ پر ختم ہوتے ہيں، واؤ کے بغير بھی درست ہيں۔
(عروض ، آہنگ اور بيان، شمس الرحمٰن فاروقي، ص: ۲۵۹)
اقبال اپنے مدعا و مطلب کے بيان کے ليے عروض کے بندھے ٹکے اوزان اور زبان کی گرامر وغيرہ کی پروا نہيں کرتے تھے۔ کيوں کہ اقبال اپنے زمانے کي ادبيات سے مطمئن نہيں تھے اور انھيں اس بات کا بخوبي ادراک تھا کہ اردو ادب ابھی تشکيل کے مرحلے ميں ہے، اس وقت جو تجربے اور رويے اپنائے جائيں گے، آنے والے زمانے ميں انھی کے مطابق لفظيات و قواعد طے کيے جائيں گي۔ اور يوں بھی قواعد کے معمولی معمولی اصول کي پابندی اوسط درجے کے شعرا و ادبا کو زيب ديتی ہے۔ اقبال جيسا عظيم شاعر نئی طرح ڈالنے کا روادار ہوتا ہے۔ اسی ليے شمس الرحمٰن فاروقی کو کہنا پڑا کہ اگر اقبال نہ پيدا ہوئے ہوتے اور ان کی شاعری ۱۹۰۵ اور ۱۹۲۳ کے درميان اپنے شباب پر نہ آئی ہوتی تو اردو شاعری کی زبان آج بھی داغ و حالی کی زبان ہوتی۔
(لفظ و معنی، شمس الرحمٰن فاروقی، ص:۴۶)
اقبال کا تصور ادب بھي سرسيد اسکول کی توسيع ہے۔ حالی کی طرح اقبال بھی ادب ميں اخلاق پر زور ديتے ہيں اور مخرب اخلاق آرٹ کو سماج کے ليے ناسور قرار ديتے ہيں۔ بلکہ ايک جگہ تو اقبال نے لکھا بھی ہے کہ ايسے ادب کو حکومت کو ممنوع قرار دينا چاہيے۔ يعنی آزادي اظہار کے نام پر حياسوزی اور تکريمِ انسانيت سے گرے ہوئے آرٹ کی معاشرے ميں کوئی جگہ نہيں ہونی چاہيے۔ الغرض اقبال کا تصور ادب وہی ہے جسے آج ہم تعميری ادب يا اسلامی ادب کے نام سے موسوم کرتے ہيں۔

Muhammad Sajid Nadwi
Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi
Mob: 8709108154