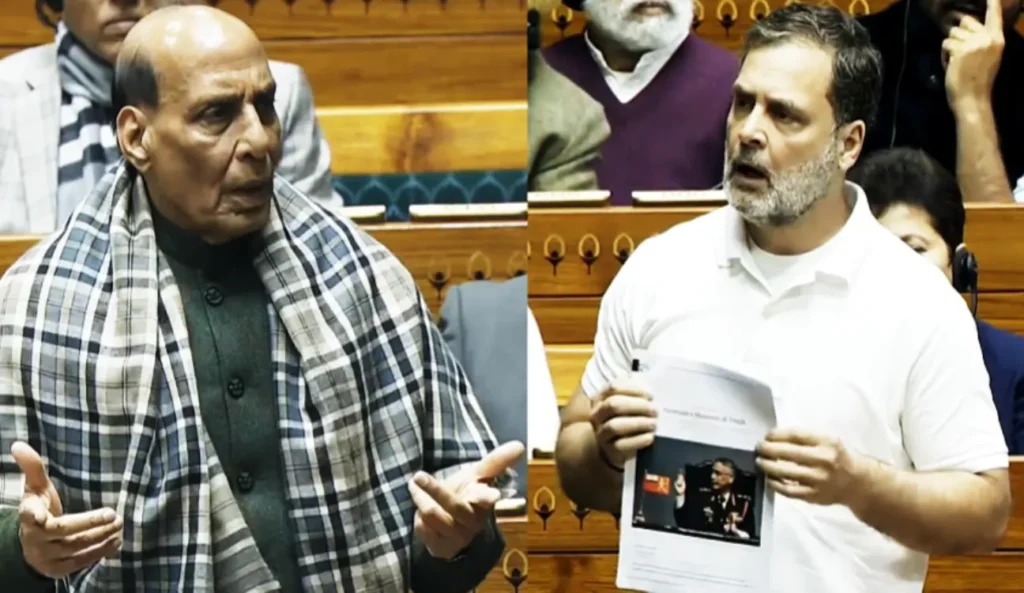ایمان: انسانیت کی اصل اور بندگی کی بنیاد

مخدوم شاہ طیب بنارسی
ایمان تمام نیکیوں کی اصل اورجملہ عبادتوں کی جڑ ہے۔کوئی عبادت وطاعت درستیِ ایمان کے بغیر صحیح نہیں ہوسکتی۔ پہلی چیز جو کسی بندہ پر فرضِ عین ہے، وہ ایمان ہے اورایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ ہیں۔
ایمان دو قسموں پر ہے: مومنِ محقق کا ایمان اور مومنِ مقلدکا ایمان۔
جو شخص خداے تعالیٰ کے ایک اور قادر و بے نیازہونے پر تقلیداً ایمان لاتا ہے اور اِس پر اُس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور’’ ایمانِ مجمل‘‘ یا ’’ ایمان مفصل ‘‘کے کلموں کو اپنی زبان پر لاتااور کہتا ہے کہ مسلمان ایسا کہہ کر مسلمان ہوجاتے ہیں، اس لیے ہم بھی ایسا کہہ کر مسلمان ہوجاتے ہیں، وہ مومنِ مقلد ہوتا ہے۔ ایمان کی یہ نوع بعض بزرگوں کے نزدیک درست نہیں ہے۔
’’کشف الاسرار‘‘ میں ہے :
’’ ایمانِ مجمل فقہا کے نزدیک معتبر ہے؛لیکن متکلمین کے نزدیک ایمان مفصل معتبر ہے، ایمان مجمل نہیں‘‘۔
’’تمہید ابوشکور سالمی‘‘ میں ہے :
’’اکثر علما کے نزدیک ایمان مفصل معتبر ہے نہ کہ ایمان مجمل، اس لیے ایمان مفصل لاناچاہیےتاکہ اس کا ایمان تمام معتبر علما کے اتفاق سے درست ہو جائے۔وَاللہُ اَعْلَمُ بِالصَّوابِ‘‘۔
حضرت تاج العلما ءکے بعض مسودات میں بھی اسی طرح ہے۔
مومنِ محقق: وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ایمان لائےاورتحقیق کے ساتھ جانے۔
یہ ایمان دو اقسام پر مشتمل ہے: ایمانِ مجمل اور ایمانِ مفصل۔
ایمانِ مجمل کا مقصود کلمۂ طیبہ اورکلمۂ شہادت ہے۔
اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ (مومن محقق) جانے کہ عا لم کو پیدا کرنے اور اسے ظہور بخشنے والا ایک ہے جس کا’’ ایک ہونا‘‘عدد کی رو سے نہیں یعنی وہ اس طرح ’’ایک‘‘نہیں ہے جیسے کہ گنتی کا ایک ہےکہ یہ دوسرے عدد کا مقابل ہوتااور نصف، ثلث،رُبع اور خمس[۱] وغیرہ اجزامیںتقسیم ہوتا ہے۔اس کے برخلاف ’’ ایک‘‘ اسے کہتے ہیں جو ایسا نہیں ہے کیوں کہ اِن چیزوں سے وہ منزہ وپاک ہے۔ وہ اپنی حقیقت کے ساتھ ایک ہے نہ کہ کسی کے اعتبار ونسبت سے۔
اگر ایک خدا سےزیادہ خدا ہوتے تو عالَم و اہل عالمَ اس شکل و صورت پر نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :
لَوکانَ فِیْھِمَااٰلِھَۃٌ اِلاَّ اللہُ لَفَسَدَتَا.[’’اگرزمین وآسمان میں اللہ کے علاوہ کئی معبود ہوتے، تو وہ ضرور غیر منظم اور برباد ہوجاتے‘‘۔]
وہ ہمیشہ تھااورہے اورہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی اسی کے لائق ہے۔اس کاکوئی شریک و سہیم نہیں، جیسا کہ آیت مبارکہ قُلْ ہُوَ اللہُ اَحَدٌ اللہُ الصَّمَدُ [’’ کہہ دو اللہ ایک ہے،اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے‘‘]اس کی قائل ہے ۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا،چناں چہ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ [’’ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جَنا گیا‘‘] اس پر ناطق ہے اورنہ کوئی شی اس کے اور نہ وہ کسی کے مثل ہے، جیساکہ وَلَمْ یَکُنْ لَّہُ کُفُوًا اَحَدٌ[’’ اور اس کا کوئی ہمسر اور مثل نہیں‘‘]اس پر حجت ہے۔ وہ کم وکیف سے پاک اور بے مثل و بےمثال ہے، نہ وہ کسی چیز کی طرح ہے نہ کوئی چیز اس کی طرح ۔ لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْ ءٌ وَہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ [’’اس کے مثل کوئی چیزنہیں، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے‘‘].وہ ہر چیز کاعالم ہے اور اس کا علم قدیم ہے – وَھُوَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیْمٌ.وہ حق ہے اور تمام اشیا کی حقیقت ثابت ہے۔ چناںچہ اہل حق کا قول ہے: حَقَائِقُ الْاَشْیَائِ ثَابِتَۃٌ [’’چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں‘‘۔]’یہ اشیاخیالِ باطل نہیں جیسا کہ اہل بدعت اور اہل باطل(ان سب پر اللہ کی لعنت ہو!) کا ایک گروہ پیدا ہوگیا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی شی کی کوئی حقیقت نہیں، تمام چیزیں محض خیال اور نمائش ہیں۔ اس کا ایسا کہنا دین ہے نہ اسلام اورتوحید ہے نہ شریعت بلکہ یہ ظاہراً وباطناً کفر ہے۔
سوال: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کا ارشاد گرامی ہے :
إِنَّ اَصْدَقَ مَاقَالَ الْعَرَبُ قَوْلُ لَبِیْدٍ : اَلَا کُلُّ شَیْ ءٍ مَا خَلاَ اللہَ بَاطِلُ[’’ان میں سب سے سچی لبید شاعر کی یہ بات ہے: آگاہ ہو جائو ! اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے‘‘۔]
یہ ارشادبظاہر بدعتیوں کے قول کے موافق ہے لیکن یہ موافقتِ ظاہری درست کیوںکر ہوگی جب کہ پیغمبرانِ گرامی اور ان کی شریعتیں، آسمان و زمین، آفتاب و ماہتاب ، ستارے ، جنت و دوزخ اور ان کے عجائبات سبھی حق تعالیٰ کی مصنوعات اور اشیا ہیںاس لیے ارشادِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا معنی ہیں؟
جواب: حق باطل کی ضد ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دودو قسمیں ہیں :
(۱)حق من کل وجہ[۲] ۔(۲)حق من وجہ دون وجہ۔[۳]۔(۳) باطل من کل وجہ[۴]۔(۴) باطل من وجہ دون وجہ[۵]۔
حق من کل وجہ خداے تعالیٰ کی ذات ہے جو واجب الوجود بنفسہ ہے، فنااس کے لیے محال ہے، اس کی ذات پاک کسی بھی وجہ سے تناہی پذیر نہیں ۔
باطل من کل وجہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے جس کے لیے بنفسہ عدم لازم اور ہستی محال ہے۔
خلق خدا من وجہ حق ہے اور من وجہ باطل اس لیے کہ وہ اصل میں نیست تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے ’’ ہست ‘‘ کیا اور وجود بخشاتو موجود ہوا۔
یوں رسول علیہ السلام نےمَازَاغَ الْبَصَرُوَمَاطَغیٰ[[’’کافروں کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتاجب وہ عذابِ دوزخ کو دیکھ لیں‘‘۔ ] کی راست بینی کی نظر سے ہر چیز کو اس طرح دیکھا کہ’’وہی(اللہ) ‘‘ اپنی ذات اور اپنی اصل کے اعتبار سے موجود ہے اوراسی کاوجودبطورِعاریت نہیںہےاِس لیےانھوںنےخداےتعالیٰ کےسواہرچیزکو ’’نیست‘‘دیکھا ۔
عارف ربانی،روشن بتجلی سبحانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
ہرچہ بینی یار ہست اغیار نیست
غیر او جز وہم وجز پندار نیست
از جمالِ وَ ہُوَ مَعَکُمْ جلوہا است
لیک ہر کس لائق دیدار نیست
’’جوچیز بھی تم دیکھتے ہو وہ یار ہے غیر نہیں، اس کا غیر وہم وخیال کے سواکچھ نہیں ۔ تمام چیزیں وَھُوَمَعَکُمْ کےجمال کے جلوے ہیں لیکن ہر شخص دیدار کے لائق نہیں‘‘۔
ایمانِ مفصل سات چیزوں پر موقوف ہے اور وہ یہ ہیں :
(۱) اللہ پر ایمان جو خالقِ عالم اور بطور ِعموم اولادِ آدم کا رازق ہے۔
(۲)اس کے فرشتوں پر ایمان جو اس کے فرماںبردار بندے ہیں اور کبھی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔
(۳) اس کی کتابوں پر ایمان جو حق ہیں اور خداے تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجی گئی ہیں جن کے لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جیسے’’ توریت‘‘ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر،’’انجیل‘‘ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر،’’زبور‘‘ حضرت دائود علیہ السلام پر،’’قرآن مجید ‘‘ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اوردیگر تمام صحائف باقی رسولانِ عظام علیہم السلام پرجیسے دس صحیفے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام پر، پچاس صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر، تیس صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اوردس صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔اس طرح ایک سو صحائف اور چار کتابیں نازل کی گئیں۔ [بستان ابواللیث ]
کتب اور رسولانِ گرامی کا حصر دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے اس لیے ایمان لانے والے کویہ کہنا چاہیے کہ میں بغیر کسی حصر وشمار کے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جملہ کتابوں اوران تمام پیغمبروں پر ایمان لایا جو مخلوقِ خدا میں سب سے بہتر اور بزرگ تر ہیں اور مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ان میں سب سے اول سیدنا آدم علیہ السلام اور سب میں آخر محمد رسول اللہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف ہیں۔ان میں بعض کی بعض پر فضیلت جائز ہے۔
ارشادِخداوندی ہے :
تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَہُمْ عَلٰی بَعْضٍ. [’’یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی‘‘۔[
ان میںسب سے افضل ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چناںچہ ’’قرآن مجید‘‘ آپ کی افضلیت پر ناطق ہے :
وَاِذْ اَخَذَ رَبُّکَ مِنْ م بَنِیْ آدَمَ مِنْ ظُہُوْرِہِمْ ذُرِّیَتَہَمُ. [’’اوریاد کرو جب تیرے رب نے اولاد ِآدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی‘‘۔]
حدیث پاک میں ہے :
أَتَتَہَوَّکُوْنَ کَمَا تَھَّوَکَتِ الْیَہُوْدُ وَالنَّصَارَیٰ وَاللہِ لَوْکَانَ مُوْسٰی حَیًّا لَمَاوَسِعَہُ إِلاَّ اتِّبَاعِیْ.
[’’کیا تم بھی ایسے ہی سرگشتہ و حیران ہوجائوگے جیسے کہ یہودونصاری سرگشتہ ہوگئے۔ بخدا اگر موسیٰ (علیہ السلام) زندہ ہوتے تو میرے اتباع و پیروی کے سواان کے لیےکوئی چارہ نہ ہوتا اور یقیناً وہ میرا ہی اتباع وپیروی کرتے‘‘۔[
(۴) آخری دن یعنی روزِ قیامت پر ایمان جو بلاشبہہ آنے والا ہے۔
ارشادِ خداوندی ہے:
وَأَنَّ السَّاعَۃَ آتِیَۃٌ لاَّرَیْبَ فِیْہَا.[’’اوربے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شبہہ نہیں ہے‘‘۔[
(۵) جنت و دوزخ اور ان کے عجائبات پر ایمان۔
(۶)اچھی اور بُریتقدیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر ایمان،یعنی بندے سے جو بھی نیکی اور بدی صادر ہوتی ہے، وہ خدا کی پیدا کی ہوئی اور بندے کا کسب ہے لیکن اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ارادہ فرماتا ہے اور یہ اسی کے حکم و مشیت اورامر و پسند و رضا سے ہوتی ہیں اور برائیاں بھی اسی کی تقدیر، اسی کے حکم اوراسی کی مشیت سے ہوتی ہیں لیکن ان میں اس کا امر، اس کی پسند اور اس کی رضاشامل نہیں ہوتی۔
تقدیر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں، جیسے خداے تعالیٰ کا ارشاد ہے :
إِنَّا کُلَّ شَیْ ءً خَلَقْنَاہُ بِقَدَرٍ.[’’بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ کے مطابق پیدا فرمایا ‘‘۔]
[’’بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ کے مطابق پیدا فرمایا ‘‘۔]
’’عمدہ‘‘ میں ہے :
اَلتَّقْدِیْرُ بَحْرٌعَمِیْقٌ مَنِ انْغَمَسَ فِیْہِ ضَلَّ. [’’تقدیرایک گہرا سمندر ہے جو شخص اس کی تَہ میں گیا، گمراہ ہوگیا‘‘۔ [
تقدیرکامسئلہ اعتقاد ی ہے،اس میںبحث نہیں کرنی چاہیے،کیوں کہ وہ ہماری عقلوں کے دائرۂ ادراک سے باہر ہے،اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :
’’مجھے عقائد و احکام بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا نہ کہ قضا وقدرمیں بحث کرنے کے لیے‘‘۔
(۷)موت کے بعد بعث پر ایمان۔اس کا مطلب ہے:موت کا جام پینے کے بعد جملہ جن واِنس اورپرندوں اور جانوروں کا دوبارہ زندہ کیا جاناحق ہے۔
یوم البعث ایسا دن ہے جس میں تمام مخلوقات میدانِ حشر میں جمع کی جائیں گی، حساب و کتاب ہوگا، میزانِ عمل نصب کیا جائے گا اور پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط دوزخ کی پشت پرہےجو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیزہے۔ لوگ اپنے اعمال کی قوت اور خداے تعالیٰ کی مہربانی سے اس پر سے گزریںگے۔ بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض تیزرفتار گھوڑے کی طرح، بعض پیدل چلنے والے کی طرح اور بعض چیونٹیوں کی چال کی طرح۔
ایمان کے تیئیس(۲۳)رکن ہیں :
چھ دل سے، سات زبان سے، پانچ جوارح سےاور پانچ خارجِ جوارح سے تعلق رکھتےہیں۔ پہلے چھ رکن جن کا تعلق دل سے ہے،یہ ہیں:
(۱)پروردگار کواس کی اِس وحدانیت کے ساتھ پہچاننا کہ وہ وَحْدَہٗ لَاشَرِیْکَ لَہُ [۱] ہے۔(۲) یہ ماننا کہ وہی تمام عالَموں کا پیدا کرنے والا۔(۳)روزی دینے والا۔ (۴) حفاظت کرنے والا۔(۵) مددگار اور(۶) احوالِ نیک وبد و ظاہر وباطن سے آگاہ ہے۔
سات رکن جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں،یہ ہیں:
(۱)خداے تعالیٰ،(۲)تمام فرشتوں(۳)تمام کتابوں،(۴)تمام پیغمبروں، (۵) روزِ قیامت،(۶) نیک وبد تقدیر اور(۷) موت کے بعد بعث پر ایمان لانا ۔
پانچ رکن جو جوارح سے تعلق رکھتے ہیں،یہ ہیں:
(۱) وقت پر نمازِ پنج گانہ ادا کرنا(۲) جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس کے روزے رکھنا،(۳) مالکِ نصاب ہو تو زکات ادا کرنا،(۴) زادِسفر اور سواری کی استطاعت ہو تو خانۂ کعبہ کا حج کرنا اور(۵) غسلِ جنابت کرنا ۔
پانچ چیزیں جن کا تعلق خارجِ جوارح سےہے،یہ ہیں:
(۱)سلطانِ اسلام کی اطاعت کرنا۔
(۲) ائمہ وموذنین کی اطاعت کرنا ۔
(۳) موزوںپر مسح کی تصدیق ۔
(۴)عید الفطر اور(۵) عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تمام مثالیںتین ارکان:
(۱)زبان سے اقرار،(۲)دل سے تصدیق اور(۳) جوارح سے عمل کی فرع اور ان کا ثمرہ ہیں۔
امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک رکن صرف دو ہیں:
(۱)زبان سے اقراراور (۲)دل سے تصدیق ۔
شرائطِ ایمان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ غیب پر اسی طرح ایمان لائے جیسا ہم نے بیان کیا یعنی تمام نادیدہ امور کی انھیں دیکھنے سے پہلے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے ان کا اقرار کرےاسی لیے ’’ایمانِ بأس‘‘درست نہیںہے۔ ایمان بأس یہ ہے کہ کوئی شخص آخرت کے احوال جیسے جنت ودوزخ کو جاں کنی کے عالم میں دیکھ کر ان پر ایمان لائے۔
منقول ہے کہ مرنے کے وقت ہر کافر ایمان لاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت اپنی جگہ دوزخ میں د یکھ لیتا ہے، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔
ارشادِ خداوندی ہے :
فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُہُمْ اِیْمَانُہُمْ لَمَّا رَاَوْابَاْسَنَا. [’’کافروں کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتاجب وہ عذابِ دوزخ کو دیکھ لیں‘‘۔
لیکن مومنوں کے لیےگناہ سے توبۂ بأس کرنا درست ہے کیوں کہ ارشادِ ربانی ہے:
اِنَّہُ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ[’’وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے‘‘۔
(ماخوذ از صلاۃ طیبی معروف بہ دینی احکام،ص:73 تا 81) ،مصنف :مخدوم شاہ طیب بنارسی ،مترجم: مولانا سیف الدین شمسی ، نظر ثانی : مولانا محمد عارف اللہ فیضی مصباحی ،مرتب: ابراررضامصباحی ،مطبوعہ شاہ عبد العلیم آسی فائونڈیشن دہلی2023ء)